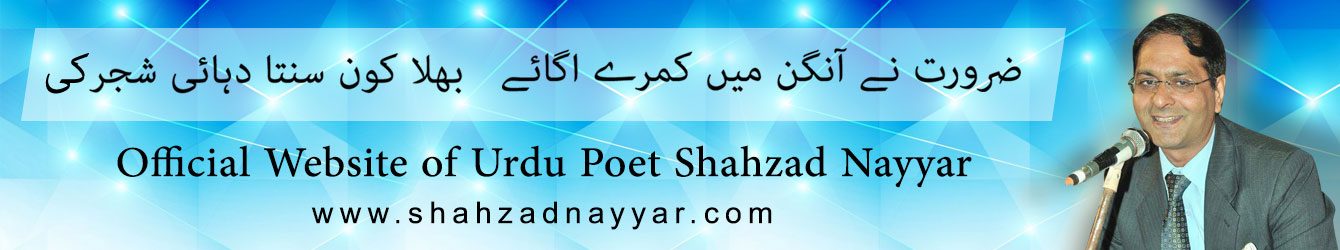Abbu Ji
ابّو جی
شہزاد نیّرؔ کی ایک پرکشش تحریر
ماں باپ پر لکھتے ہوئے یادوں کے ایسے تابڑ توڑ حملے ہوتے ہیں کہ قلم شکست کھا جاتا ہے۔ کئی بار لکھنا چھوڑ کر ماضی کی لہروں پر ڈولنا اور یادوں کی رَو میں بہتے چلے جانا اچھا لگتا ہے۔ خیالوں کے سمندر میں ڈوبتے ابھرتے جو کچھ اپنے والد صاحب کے بارے لکھ سکا وہ پیشِ خدمت ہے۔
شناختی کارڈ کے مطابق ابو جی 1948ء میں پیدا ہوئے۔ اس سال کا اندراج بھی دادی کے ایک یاد داشتی بیان کا مرہونِ منّت ہے۔
’’لُوٹ مار ختم ہو گئی تھی۔ ہندو سکھ جا چکے تھے۔ اُدھر سے مسلمان آکر ہندوئوں سکھوں کے گھروں میں آباد ہو چکے تھے۔ جب میرا محمد رفیق پیدا ہوا‘‘۔
شاید یہی سبب تھا کہ ابو جی کے شناختی کارڈ پر صرف پیدائش کا سال درج تھا۔ دن اور مہینے کا کچھ مذکور نہ تھا۔ ہوتا بھی کیسے۔ دادی دادا کو جنوری فروری مارچ آتے نہ تھے، شناختی کار و الے پھاگن چیت، اسوج کاتک لکھتے نہ تھے۔ ابو جی آٹھ سال کے ہوئے تو اپنے والد کے ساتھ کھیتوں پر جانے لگے ہمارے دادا جی ٹھیکے پر زمین کاشت کرتے تھے۔ ان دنوں ابو کا کام بس کنویں کے بیل ہنکائے رکھنا تھا۔
کنواں عمر کے آخری برسوں تک ان کے ساتھ رہا ۔ کنویں کے آلات اورسازو سامان کے نام، تمام کے تمام، عمر بھر انہیں یاد رہے۔ وہ کنویں کو بطور استعارہ استعمال کر کے ہمیں زندگی کی کئی باتیں سکھاتے تھے۔
٭ سر پہ نگران نہ ہو تو کنویں کے بیل بھی رُک جاتے ہیں۔
٭ کاروبار کنویں کی مثال ہوتا ہے۔ ایک بالٹی پانی نکال لو یا ڈال دو، اسے کچھ فرق نہیں پڑتا۔
٭ کنویں کی ماہل (زنجیر) کے ساتھ کئی ٹِنڈیں (برتن) بندھی ہوتی ہیں۔ ماہل چلتی ہے تو کوئی ٹِنڈ پوری بھری ہوئی آتی ہے، کوئی آدھی تو کوئی پونی۔ سب اپنا اپنا پانی پاڑچھے میں انڈیل دیتی ہیں۔ پھر کچھ پتہ نہیں چلتا کس نے کتنا پانی ڈالا‘‘۔ اس مثال سے وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ساجھے کے کاروبار میں زیادہ حساب کتاب نہ کرو کہ کون کتنا کام کر رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ چلتے کاروبار میں پروڈکشن بڑھانے پہ دھیان دو کوئی آئٹم زیادہ منافع دے جائے گی تو کوئی کم۔ کنواں چلتا رہے تو پانی بہتا رہے گا۔
٭ کنواں چلا کر یہ بھی دیکھو کہ ساری ٹِنڈیں خشک تو نہیں آ رہیں (کوشش کے ثمر پر بھی نظر رکھو)
٭ جب کسی کام کی آمدن اُسی پر خرچ ہو جائے تو کہتے ’’کنویں کی مٹی کنویں پر ہی لگ گئی۔‘‘
ہمارے بچپن میں سردیوں کی لمبی راتوں کی ایک دلچسپ سرگرمی ’’بجھارتیں بُوجھنا‘‘ تھی۔ امّی کے پاس پہیلیوں کا وسیع ذخیرہ تھا۔ ’’ماں جمّی نئیں، پُت کوٹھے تھے‘‘ (ماں پیدا نہیں ہوئی، بیٹا چھت پر پہنچ گیا) ہم سب ہار جاتے تو وہ کہتیں ’’آگ اور دھواں‘‘۔
’’ماں لیراں پتیراں، پُت تُگ مُگلا‘‘۔ (ماں کترنوں کی طرح بکھری ہوئی اور بیٹا موٹا تازہ، گول مٹول)۔ پھر یہ جانتے ہوئے کہ ہم یہ بجھارت نہ بوجھ پائیں گے، خود ہی بتا دیتیں ’’تربوز کی بیل اور تربوز‘‘ امی کے برعکس ابو کی پٹاری میں ایک ہی پہیلی ہوتی۔
آ ٹانگا، پا ٹانگا، وچ ٹلم ٹلیاں۔ آون کونجاں دین بچڑے، اسی ندی نہاون چلیاں… اس بجھارت کا اُردو ترجمہ بہت مشکل ہے۔ آزاد مفہوم یہ ہے کہ ایک تانگے میں دوسرا تانگا پرویا ہوا ہے۔ اس کے بیچ گھنٹیاں بندھی ہیں۔ کُونجیں آتی ہیں، بچے دیتی ہیں اور پھر کہتی ہیں ہم ندی میں نہانے جا رہی ہیں۔‘‘
اتنی پیچیدہ اور طویل بجھارت ہم کیسے بوجھ سکتے تھے۔ وہ ایک خوشی سے کہتے۔ ’’کنواں اور کنویں کی ٹِنڈیں‘‘ (ٹِنڈ۔ مٹی کا وہ برتن جو کنویں کی زنجیر سے بندھا ہوتا ہے)
ڈھائی ہزار سال قدیم کنواں (Persian Wheel) آخری عمر تک ان کی یادوں سے محو نہ ہوسکا۔ بات بات میں کنواں آٹپکتا۔ ماڈل ٹائون (گوجرانوالہ) کے بارے بات کرتے ہوئے کہتے ’’جہاں تم قطار اندر قطار پکّی کوٹھیاں دیکھتے ہو وہاں دور دور تک کھیت تھے اور ان کو سیراب کرتے بیلوں والے کنویں۔‘‘
ابو کے بچپن کا گوندلانوالہ (گوجرانوالہ) ایک نئی کروٹ لے رہا تھا۔ گائوں کی غیر مسلم آبادی بھارت جا چکی تھی اور جالندھر، امرتسر، ہوشیار پور سے آئے ہوئے پنجابی مسلمان مہاجر آباد ہو چکے تھے۔ دادا جان ایک ایک مکان دکھا کہ ابو کو بتایا کرتے تھے کہ یہ میرے فلاں ہندو دوست یا سکھ یار کا مکان ہوا کرتا تھا۔
دادی بتاتی تھیں کہ پوری ’’لُوٹ مار‘‘ (دادی نے ہمیشہ قیام پاکستان کو اسی لفظ سے یاد کیا) میں تمہارے دادے نے کچھ نہ لُوٹا۔ لوگ بند گھروں کے تالے توڑ کر سامان نکال رہے ہوتے اور یہ پاس سے گزر کر گھر آجاتے۔ میں طعنہ دیتی تو غم و غُصے سے کہتے ’’اپنے دوستوں یاروں کے گھر لُوٹ لوں کیا؟ اپنے اندر کو مار دوں؟‘‘ اپنے اندر کی اچھائی سے سیراب انسان نے بہتی گنگا میں ہاتھ نہ دھوئے اور غریب کاشتکار ہی رہ گیا۔ آرائیں کو کاشت کاری کے سوا کچھ آتا نہیں اور اتنی زمین تھی نہیں۔ پاکستان بنا تو اتنا ہوا کہ پہلے دادا جان سکھوں کی زمین کاشت کرتے تھے اب مسلمان زمیں داروں کی۔ گھر میں غربت کے ببول اُگے ہوئے تھے۔ دادا جی نے اپنے کم سن بیٹوں محمد صدیق اور محمد رفیق (ابّو) کو کھیتوں میں کام پر لگا لیا۔ ابو جی نے ساری زندگی یہ جملہ فخر سے بولا ‘‘ میں سات آٹھ سال کا تھا جب میں نے کام کاج اور محنت مزدوری شروع کر دی تھی۔
سچ تو یہ ہے کہ سخت محنت ابّو کی ہڈیوں میں رچ گئی تھی۔ کام کئے بغیر انہیں چین نہیں آتا تھا۔ کسی دن تھکا دینے والا سخت کام کرتے تو کہتے۔ آج کھانا کھانے کا بھی مزا آئے گا اور نیند بھی اچھی آئے گی۔‘‘
اواخر عمر میں بھی، جب تک ان میں سکت رہی، پوری ذمّہ داری سے اپنی فیکٹری میں کام کرتے رہے۔ گھر کی چیزوں کی خود مرمت کرنا یا پاس کھڑے ہو کر کاری گر سے کروانا، ان کا من پسند مشغلہ تھا۔ اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنا انہیں تاحیات مرغوب رہا۔
آئیں واپس ابّو کے بچپن میں چلتے ہیں۔
بیگانے کھیت کاشت کرنے سے آمدن محدود ہی ہوا کرتی ہے ۔ اُدھر کُنبہ برابر بڑھ رہا تھا دادا نے کسی کے کہنے پر بارہ اور چودہ سال کے دونوں بڑے بیٹے کارخانے میں مزدور بھرتی کرا دیئے۔ گوجرانوالہ پہلے سے ہی لوہے کی صنعت میں مشہور تھا۔ ایوب خان کے دور میں صنعتی ترقی ہوئی تو دھڑا دھڑ نئے کارخانے لگے۔ کھیت مزدور، صنعتی مزدور بننے لگے۔ ابو بتایا کرتے تھے، گائوں سے شہر تک کا دس کلو میٹر فاصلہ وہ ہنستے کھیلتے پیدل طے کیا کرتے تھے۔ جلدہی تیسرا بھائی بھی ساتھ مل گیا۔ کچی سڑک پر تانگے چلا کرتے تھے لیکن اتنی عیاشی کسے میسر تھی کہ محنت مزدوری سے کمایا پیسہ کرائے بھاڑے میں اُڑائے۔ منہ اندھیرے روانہ ہو کررات گئے گھر پلٹنا، کئی سال تک یہی زندگی رہی۔ جانے کب سڑک پکّی ہوئی، کچھ آسودگی آئی اور یہ لوگ تانگوں، بسوں پر سفر کر کے شہر گوجرانوالہ جانے لگے۔
ایک واقعہ انہوں نے کئی بار سنایا۔ ابو اور چچا دن بھر کی مزدوری کے بعد پیدل گائوں آ رہے تھے۔ تھکے ہارے تھے۔ کسی نے زیرِ تعمیر مکان کی چھت پر مٹی ڈالنے کی عارضی مزدوری کی پیشکش کر دی۔ بس پھر کیا، دونوں بھائی جٹ گئے۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد تک سر توڑ محنت کی اور اضافی آمدن کی خوشی اٹھائے گھرلَوٹے۔
غریب گھرانوں کے بچے جلدی سمجھ دار اور ذمّہ دار ہو جاتے ہیں۔ ان وقتوں میں سولہ اٹھارہ سال کے بیٹے کے باپ کو محلّے دار تنبیہہ کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اس کی شادی کر دو۔ابو بتاتے تھے کہ پینسٹھ کی جنگ والے سال ان کی منگنی ہوئی اور اس سے اگلے سال شادی، ہماری امّی، ابوّ کی خالہ زاد تھیں ۔ ذرا سے خوش حال گھرانے سے آئی تھیں۔ وجہ یہ ہے کہ نانی کے محض پانچ بچے تھے اور دادی کے دس (دو فوت بھی ہوئے تھے!) ۔ ابو کی بارات دو سجے ہوئے ٹانگوں پر سوار کچے راستوں پر قریبی گائوں قلعہ دیدار سنگھ گئی تھی۔ واپسی پر دلہا اور دلہن الگ تانگوں پر بیٹھ کر آئے!۔ یہ 1966ء کا سال تھا اورابو کی عمر18 سال۔ رفتہ رفتہ وہ محض صنعتی مزدور سے ترقی پا کر خراد مشین کے کاریگر بن گئے۔ یہ ان کی زندگی کی ایک بہت بڑی چھلانگ تھی۔ میں سمجھتا ہوں اگر وہ یہ خلیج نہ پاٹتے تو کبھی کارخانوں کے مالک نہ بن سکتے۔ اسی لئے ساری زندگی وہ اپنے استاد (جن سے خراد مشین کا کام سیکھا) کی بے پناہ عزت کرتے رہے۔ باقاعدہ اپنے استاد سے ملنے جاتے حتیٰ کہ وفات سے چند ماہ پہلے تک بھی، فالج کے باوجود، انہیں سلام کرنے جاتے رہے ۔ اندر ہی کوئی اعتراف و احترام ہوتا ہے ورنہ کون یوں زندگی بھر شکر گزاری کی رسم نبھاتا ہے۔
شادی کے بعد ابو نے محنت کا دورانیہ بڑھا دیا۔ اکثر اوور ٹائم لگاتے تھے۔ گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں اوور ٹائم سے بنتی تھیں۔ ایک ناقابلِ شکست مستقل مزاجی کے ساتھ وہ ذاتی کاروبار کے لئے رقم بھی پس انداز کرتے رہے۔
اُسی زمانے کی ایک یاد میری زندگی کی اوّلین یادوں میں سے ہے۔ چھت پر سردیوں کی خوشگوار دھوپ میں چار پائی بچھی ہے۔ ابو ’’لوئی‘‘ اوڑھ کر بیٹھے ہیں ان کی گود میں ہم دونوں بھائی چھپے ہوئے ہیں۔ یہ وہی ’’لوئی‘‘ ہے جس کی بابت بُلھے شاہ فرما گئے ہیں۔
چٹی چادر لا سٹ کُڑیے، پہن فقیراں لوئی
چٹی چادر داغ لگیسی، لوئی داغ نہ کوئی
اُبو لوئی کا کبھی ایک کونہ گرا کر ہمیں چھپاتے ہیں اور پھر اوپر اٹھا کر ڈھونڈ لینے کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ اس کھیل میں کچی اُون کی لوئی ہمیں چبھتی بھی بہت ہے کاش اس لوئی کی چبھن کوئی لوٹا دے!
زندگی بھر ابو جی ایک اصول کا پرچار کرتے رہے۔ سولہ آنے کمائو تو بارہ آنے خرچ کرو، چار آنے بچائو ۔ اس پالیسی کو انہوں نے مالی آسودگی کا فارمولا بنا کر دکھایا۔ اپنی بچت سے ذاتی کاروبار شروع کیا اور پھر فیکٹریوں، جائیدادوں کے مالک بنے
لوہا پگھلانے والی بھٹی اور لوہا چھیلنے والے ’’رَندے‘‘ سے لے کر موٹریں اور پنکھے بنانے والی فیکٹری تک، مسلسل مشقت اور کامل دیانت کا ایک لمبا سفر ہے۔
میں چوتھی پانچویں میں پڑھتا تھا، گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ مجھے اپنے ساتھ شہر لے جاتے۔ چھوٹے موٹے کام کراتے اور بعد میں خوب پھل کھلاتے ۔ ایک دو سال بعد وہ مجھ سے زیادہ کام کرانے لگے ایک دن میری انگلی مشین میں آگئی اور ناخن کا ایک حصہ کٹ گیا (اب تک وہ ناخن دوسروں سے مختلف نظر آتا ہے) ابو نے کس کر پٹی لپیٹی اور تانگے پر بٹھا کر گائوں روانہ کر دیا۔ گھر پہنچنے تک پٹی سرخ ہو چکی تھی اور خون بھی ٹپک رہا تھا۔ امی نے سر پیٹ لیا۔ ڈاکٹر سے باقاعدہ نئی پٹی کرائی۔ شام کو ابو گھر آئے تو ان سے خوب لڑائی کی۔ میرا کارخانے جانا موقوف ہوا اور مجھے ٹیوشن پہ ڈال دیا گیا۔ میں آٹھویں نویں میں پہنچا تو ابو کی بہت خواہش تھی کہ پڑھائی چھوڑ کر ان کے ساتھ کاروبار میں لگ جائوں۔ مصیبت یہ کہ میں پڑھائی میں تیز تھا۔ اہل محلہ سمیت اساتذہ کی بھی یہی رائے تھی کہ اس لڑکے کو پڑھنے دیا جائے۔ 31 مارچ کو نتیجہ آتا تو ہر بار میری اوّل پوزیشن ہوتی۔ وہ رنگین کاغذ میں لپٹے انعام کو دیر تک دیکھتے رہتے اور کچھ سوچتے رہتے۔ بعد میں انہوں نے میرے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ کاروبار میں لگالیا حالانکہ وہ پڑھائی میں مجھ سے بھی آگے تھا! گوجرانوالہ کے دستور کے مطابق ابو جی نے ہم بھائیوں کو پہلوانی سکھائی۔ ہمارے مکان کے پیچھے ہمارا اپنا ایک خالی پلاٹ تھا جس میں اکھاڑہ بنا ہوا تھا اسی جگہ ہم نے بھینسیں پال رکھی تھیں۔ سکول کے زمانے میں ہم دونوں بھائی بھینسوں کے لئے چارہ لاتے اور صبح شام اکھاڑے میں کسرت بھی کرتے۔
ابو صبح سویرے ہمیں جگا کر اکھاڑے لے جاتے۔ خود لنگوٹ باندھتے اور ہمیں لنگوٹ باندھنا سکھاتے۔ (ہمارے علاقے میں تکونی شکل کی لنگوٹی ہوتی ہے جسے ’’رومالی‘‘ بھی کہتے ہیں)۔ اپنے جسم پر سرسوں کا تیل ملتے پھر ہمارے جسموں پر تیل کی مالش کرتے۔ اس کے بعد اکھاڑہ کھود کر نرم کرنے کا مرحلہ آتا۔ کسّی چلاتے چلاتے سخت سردی میں بھی ہمیں پسینہ آ جاتا۔ اس ساری کارروائی کے بعد کُشتی لڑنے اور دائو پیچ سیکھنے کا مرحلہ آتا۔ وہ ہمارے جسموں پر مٹی ملتے ہم ان کے جسم پر، پھر وہ ہمیں خودکشی کر کے بتاتے ’’قینچی‘‘ کیسے مارنی ہے۔ ’’دھوپی پٹڑا‘‘ کیا ہوتا ہے۔
پہلوانی پھرتی اور طاقت کا امتزاج ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ اپنی پہلوانی کے قصے بھی سناتے جاتے۔ پہلے وہ ہم دونوں کے ساتھ باری باری کُشتی لڑتے پھر ہمیں کہتے کہ آپس میں لڑو۔ کبھی کبھی ہمیں دوڑ بھی لگواتے۔ اس سب کے بعد ہم مٹی میں لتھڑے جسم لئے نلکے تلے بیٹھتے تو سیروں مٹی غسل خانے کے فرش پر جمع ہو جاتی اور سرسوں کے تیل کی پیلاہٹ پانی کی سطح پر تیرتی رہتی۔ گھر پہنچ کر ’’سردائی‘‘ تیار کرنے کا مرحلہ آتا۔ مٹی کی کونڈی میں لکڑی کے ڈنڈے سے بادام رگڑرگڑ کر ہم اس میں ’’سُنڈھ‘‘ (خشک ادرک) والا پانی ڈالتے جس کی تلخی گلے کو لگتی تو ہم گہری سانسیں لیتے۔
اب سکول کے لئے تیار ہونے کا مرحلہ آتا۔ ابو تگڑا ناشتا کر کے جلدی جلدی موٹر سائیکل (بائیک کا لفظ ہم نے بہت بعد میں سنا) پر سوار کارخانے چلے جاتے اور ہم دونوں کھیتوں کی پگڈنڈیوں پر چلتے چلتے سکول پہنچ جاتے۔ ہم میٹرک میں پہنچے تو ابو کا کارخانہ ترقی کرنے لگا۔ہمارے بنے ہوئے پنکھے اور موٹریں راولپنڈی، سرگودھا، فیصل آباد اور بنوں کوہاٹ جانے لگیں۔ سخت محنت، کاروباری صلاحیتوں اور حساب کتاب کی پکی عادت کے طفیل کاروبار پھیلتا چلا گیا۔ میں حسبِ فرصت کارخانے کو وقت دیتا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں تو روزانہ جاتا۔ ویسے کبھی کبھار جا کر کھاتے لکھ دیتا۔ چھوٹا بھائی بھی (جو مجھ سے محض دو سال چھوٹا ہے) ہاتھ بٹاتا۔ دسویں کے امتحان کے بعد ابو نے بھرپور کوشش کی کہ میں پڑھائی چھوڑ کر کاروبار میں آ جائوں۔ گھر میں یہ موضوع کئی ہفتے تک زیر بحث رہا۔ امی کا ووٹ کبھی میری طرف ہوتا کبھی ابو کی طرف۔ اس اثناء میں میٹرک کا نتیجہ آگیا۔ میرے نمبروں کو دیکھتے ہوئے، اور ایک صنعت کار دوست کے مشورے سے ، انہوں نے مجھے ایف سی کالج لاہور میں داخل کرا دیا۔ دو سال بعد چھوٹے بھائی نے میٹرک کیا تو اسی طرح کی کشمکش کے بعد ابو نے اسے کاروبار پر اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ کیا کہتے ہیں ایک ایک اور دو گیارہ۔ کاروبار ترقی کرتا چلا گیا۔
یہاں سکول کے زمانے کی ایک اور کشمکش کا ذکر ضروری ہے۔ اس کشمکش کا نام ہے ’’ٹی وی‘‘۔ اس زمانے میں ٹیلی ویژن کو تمام برائیوں کی جڑ سمجھا جاتا تھا۔ مساجد میں باقاعدہ ’’ٹی وی شیطان‘‘ کے خلاف وعظ ہوتے تھے۔ بعض لوگ تو ٹی وی دیکھنا حرام سمجھتے تھے۔ ابو جی روایتی مذہبی ذہن کے مالک تھے۔ ظاہر ہے انہیں ہمارا ہمسائیوں کے گھر جا کر ٹی وی دیکھنا سخت ناپسند تھا ہم بہن بھائی پی ٹی وی کے بے پناہ دلچسپ ڈراموں کے سحر میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ ہزار بار منع کرتے، ہم دو ہزار بار جاتے۔
شاید میں آٹھویں یا نویں میں تھا جب ابو جی خود گھر میں ٹی وی لے آئے۔ پتھر میں جونک کیسے لگی، اس کا احوال خاصا طویل ہے۔ اختصار اس کا یہ کہ بچے گھر پر رہیں گے۔ کئی سال تک ابو جی خود ٹی وی پر نگاہ نہیں کرتے تھے۔ سوائے اس وقت کے جب اذان نشر ہو رہی ہوتی اور مکہ مدینہ کے مناظر دکھائے جاتے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے خبریں اور مذہبی پروگرام دیکھنے شروع کر دیئے۔ کچھ دور چل کر قوالیاں اور پھر ریشماں کے گانے… پتھر پگلا تو پگھلتا چلا گیا پھر بھی ٹیلی ویژن کے ساتھ ان کی دلچسپی کو واجبی قرار دیا جاسکتا ہے۔ آج کل تو ٹی وی کی قبولیت مذہبی حلقوں میں بھی عام ہے۔ 90,80 کی دہائی کے دیہات میں عام لوگ بھی ٹی وی سے متنفر تھے اور اسے گناہ کا گھر سمجھتے تھے۔ ایف ایس سی کے بعد میں آرمی میں چلا گیا۔ وہ خوش تو تھے لیکن بہت زیادہ نہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ میری خوشی سے خوش تھے۔ کافی مہینوں بعد انہیں پتہ چلا کہ آفیسر سلیکٹ ہونے اور سپاہی بھرتی ہونے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وہ میری پاسنگ آئوٹ پریڈ پر کاکول (ایبٹ آباد) آئے تو پاکستان ملٹری اکیڈمی کو غور سے دیکھتے رہے ’’کتنا پیسہ لگایا ہوا ہے حکومت نے یہاں، گورنمنٹ کے کام گورنمنٹ ہی جانے‘‘۔ پریڈکی شان و شوکت اور فوجی وردیوں کی چمک دھمک سے وہ کوئی زیادہ متاثر نہیں ہوئے۔ ان کی چہرے پر اتنی ہی خوشی تھی جتنی اپنے بیٹے کو برسرِ روزگار دیکھ کر ہوسکتی ہے۔
ان دنوں میں لیفٹیننٹ تھا۔ ایک بار چھٹی پر گھر آیا تو انہوں نے سب سے الگ کر کے میری تنخواہ پوچھی۔ ظاہر ہے ان کے اندازے سے خاصی کم نکلی۔ ’’اس سے زیادہ تو میں بجلی کا بل دیتا ہوں‘‘۔ انہو ں نے خلوص دل سے مجھے مشورہ دیا کہ فوج کی نوکری چھوڑ کر اپنے کارخانے آجائوں۔ ’’غیر کی نوکری سے اپنا کاروبار ہزار درجے بہتر ہے۔‘‘ میں نے نرمی سے ان کا مشورہ اِدھر اُدھر کر دیا۔ دوسری بار جب میں کیپٹن تھا، انہو ں نے یہی مطالبہ دہرایا۔ تب تک میں آرمی میں اچھا خاصا ایڈجسٹ ہو چکا تھا۔ ساتھ ہی کتابوں کا رسیا اور علم و ادب کا شوقین تھا ایک عجیب سی عینیت پسندی کا مجھ پر غلبہ تھا۔ فیکٹری، مزدور، حساب کتاب سے دلچسپی نہیں، روپیہ پیسہ اور جائیداد کو میں پرِکاہ کے برابر اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے ملائمت سے کہا ’’جتنا پیسہ زندگی گزارنے کو درکار ہوتاہے وہ مجھے فوج سے مل جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں اپنا لکھنے پڑھنے کا شوق بھی جاری رکھ لیتا ہوں۔ آپ میری نوکری کو چلنے دیں۔‘‘ وہ مان گئے
کارگل کی جنگ اور بعد ازاں سیاچن گلیشیر پر میری ڈیوٹی کے دنوں میں وہ خاصے مضطرب رہے۔ وہ پوری خبریں سنتے تھے۔ بعد میں انہیں تسلی سی ہوگئی۔ لائن آف کنٹرول اور وزیرستان کی تعیناتی کے دوران میں وہ خط، ٹیلی فون اور دعائوں پر بھروسے کے سبب وہ اطمینان میں رہے۔
میری کپتانی کے دن تھے اور پوسٹنگ لاہور میں تھی۔ یہی وہ شہر تھا جہاں وہ آسانی سے ملنے آ جاتے تھے۔ ایک بار وہ آئے ہوئے تھے۔ شام کو باہر نکلے تو آفیسرز کالونی کی سڑکوں پر بچے سائیکلیں چلا رہے تھے۔ اُسی وقت مجھے پیسے دیے۔ میں نیلا گنبد سے سائیکلیں لے آیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے پوتے اور پوتی کو سائیکل چلاتے دیکھا اور پھر واپس روانہ ہوئے۔
ابو کی زندگی کے فارمولے بہت سادہ تھے۔
پہلے نمبر پر وہ مالی آسودگی کو اہمیت دیتے تھے۔ دیانت اور محنت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا اور کاروبار کو ترقی دینا ان کی زندگی کا بڑا محور تھا۔ وہ سچائی کیساتھ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں عزت اور سہولت کے ساتھ رہنا ہے تو مالی حیثیت مستحکم کرو۔ وہی بات پنجابی کہاوت والی جیہدے گھر دانے اوہدے کملے وی سیانے (جس کے گھر روپیہ پیسہ اس کے بے وقوف بھی سمجھ دار) ۔ میں اُس وقت تو ان سے اتفاق نہیں کرتا تھا، اب زمانے کے چلن نے خوب اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ وہ ٹھیک کہتے تھے۔
دوسرے نمبر پر ان کی مذہبی ومسلکی وابستگی تھی۔ وہ خالص حنفی بریلوی ہونے کو وجہ نجات سمجھتے تھے۔ نعت خوانی کی محفلوں میں جانا اور نعت خوانوں پر پیسے لُٹانا انہیں مرغوب تھا۔ اس کے علاوہ دنگل دیکھنا کُشتی جیتنے والا پہلوان پنجابی ریت کے مطابق تماشائیوں کے آگے سے گزرتا تو اس کی مُٹھی میں پیسے ضرور تھماتے۔ گھر آکر دنگل کی قابلِ ذکر کُشتیوں کا احوال جوش و خروش سے سناتے۔ ساتھ ساتھ دائو بیچ پر فارم کر کے بتاتے۔
ابو جی پرانی وضع کے خالص انسان تھے۔ چالاکی اور بناوٹ انہیں چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ ناپسندیدگی کا فوراً اور برملا اظہار کر دیتے۔ منہ پر بات کرتے چاہے رشتے داری میں دراڑ ہی کیوں نہ آ جائے۔ بینک کی منافع بخش سکیموں میں پیسہ رکھوانا ناجائز سمجھتے۔
نیلامی والی کمیٹی کو حرام سمجھتے۔ قرضِ حسنہ کے سچے دل سے قائل تھے۔ اور فراخ دلی سے لوگوں کو قرض دیے۔ بھکاریوں کو ناپسند کرتے تھے۔ اور انہیں کاہل سمجھتے تھے تاہم بزرگ اور خواتین سائلین کو خیرات دے دیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں بے حد حساس تھے۔ پورا پورا حساب کر کے ہر سال زکوٰۃ دیتے۔
فلموں اور گانوں سے لگائو نہیں تھا۔ سوائے نصرت فتح علی خاں اور ریشماں۔ فارغ وقت نماز، تلاوت اور گپ شپ میں گزارتے تھے۔ امی کی وفات کے بعد انہیں کچھ قوالیاں اور گیت بار بار سنتے اور روتے ہم نے دیکھا۔
ابو جی کی زندگی کا سب سے بڑا سانحہ اور حادثہ امی کی اچانک وفات تھا۔ جولائی 1998ء کی ایک صبح امی حسبِ معمول تڑکے بیدار ہوئیں۔فجر کی نماز پڑھتے ہوئے جائے نماز پر ہی گر کر بے ہوش ہوگئیں۔ انہیں فوراً سی ایم ایچ گوجرانوالہ لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ دماغ کی نَس پھٹ گئی ہے۔ بے ہوشی کے عالم میں ہی چند گھنٹے میں ان کا انتقال ہوگیا۔
امی کی وفات پر ابو زار و قطار روئے۔ حالانکہ دیہات کی معاشرت میں بیوی کی وفات پر شوہر کا اونچی آواز میں رونا قدرے معیوب سمجھا جاتا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ ابو، امی کا نام لے لے کر بے اختیار روئے جا رہے تھے۔
اس وقت ابو کی عمر محض 50 سال تھی۔ ہماری سب سے چھوٹی بہن بارہ تیرہ برس کی تھی۔ (ہم سات بہن بھائی ہیں) ابو کو نارمل روٹین میں آتے آتے کئی ماہ لگ گئے پھر بھی کئی بار اچانک رو پڑتے۔ کاروبار کے علاوہ ان کی کوئی خاص سرگرمی تھی نہیں۔ گھر، فیکٹری اور مسجد اس تکون میں ان کی اداس زندگی گزرنے لگی۔ ایک آدھ سال بعد میں نے بڑی بہن اور چھوٹے بھائی سے بات کی کہ ہمیں ابو کی شادی کر دینی چاہئے۔ وہ پہلے تو ہکا بکا رہ گئے پھر انہوں نے کہا کہ باقی بہن بھائیوں کے سامنے یہ تجویز رکھی جائے لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ۔ میرا خیال ہے کہ امی کی وفات کے دو تین سال بعد کثرتِ رائے سے تجویز منظور ہوئی (سب سے چھوٹی بہن نے تجویز سے اختلاف کیا) ۔ ابو سے بات کرنے کی بھاری ذمہ داری میرے اور شہباز (چھوٹا بھائی) کے کندھوں پر آپڑی۔
یہ بات سنتے ہی ابو زار و قطار رونے لگے۔ ہم دونوں بھائیوں کے آنسو بھی گریبان تر کرتے رہے گریہ و زاری میں کوئی بات ہی نہ ہوسکی۔ دو چار ماہ بعد ہم نے دوبارہ بات کی تو انہوں نے سوچنے کا وقت مانگا۔ چھ آٹھ ماہ سوچنے میں گزر گئے۔ بالآخر انہوںنے کہا ’’میری شرائط سن لو۔ نوجوان نہ ہو۔ میری عمر سے دوچار سال کم زیادہ ہو۔ کنواری نہ ہو، بیوہ یا مطلقہ ہو۔ بانجھ ہو یا بچہ پیدا کرنے کی عمر سے گزر چکی ہو۔ آخری شرط یہ کہ لازمی ہماری ارائیں برادری سے ہو۔ اگر رشتہ داروں میں سے کوئی ہو تو اوربھی اچھا۔
اتنی کڑی شرائط سن کربھی ہم نے ہمت نہ ہاری اور دور و نزدیک چپکے چپکے خبر پھیلا دی۔ لوگ حیران بھی ہوتے تھے کہ اولاد خود اپنے باپ کا رشتہ تلاش کر رہی ہے لیکن ہم اپنا کام کرتے رہے۔ اسی کوشش میں ہمیں اپنی دور پار کی ایک رشتہ دار خاتون کا پتہ چلا۔ وہ ابو کی ہم عمر تھیں اور انہیں بچہ پیدا نہ کرسکنے کے باعث طلاق ہو چکی تھی۔ بات آگے بڑھانے سے قبل ابو کی رضا مندی لینی ضروری تھی۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے نام ابو کے سامنے رکھا۔ وہ روتے رہے اور سوچنے کا وقت مانگ لیا۔ حالانکہ وہ خاتون کو اچھی طرح جانتے تھے۔ تین ماہ بعد ابو نے ہاں کر دی۔ ہم خوش ہو گئے۔ ہم نے خاندان کے دو بزرگوں کا وفد تشکیل دیا اور انہیں رشتہ لینے روانہ کر دیا۔ جانے کیوں ہم سب بھائی بہنوں اور خود ابو کو یقین تھا کہ اُس طرف سے انکار نہیں ہوگا۔ لیکن بزرگوں کا وفد بے نیل مرام واپس آگیا۔ ابو نے صرف اتنا پوچھا۔ ’’کیا آپ لوگوں نے الگ سے خاتون کے ساتھ بھی بات کی؟ انہوں نے بتایا کہ انکار خود انہوں نے ہی کیا ہے کیونکہ بھائیوں نے سارا معاملہ انہیں پر چھوڑ دیا تھا۔‘‘
یہ انکار ابو کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوگیا۔ وہ ٹوٹ پھوٹ گئے۔ شاید وہ زیادہ ہی حساس ہو چکے تھے۔ انہوںنے سختی سے ہمیں منع کر دیا کہ آج کے بعد یہ موضوع نہیں اٹھایا جائے گا۔
ہم نے ایک آدھ سال بعد ابو کے دوستوں اور بھائیوں کے ذریعے ایک اور کوشش کی جو ناکام ہوگئی ابو نے خود کو کاروباری معاملات اور عبادات کے سپرد کر دیا۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی شادی ہو جاتی تو وہ نسبتاً بہتر زندگی گزارتے۔ خاص طور پر ان کے آخری پانچ سال تو ایسے تھے کہ قدم قدم پر مددگار، غمگسار ساتھی کی موجودگی ضروری تھی۔
فیکٹری سے واپسی پر وہ اپنے کمرے میں اگربتی سلگاتے، تلاوت کرتے، نوافل ادا کرتے۔ اس کے بعد نصرت فتح علی خاں کی قوالی ’’یاداں وچھڑے سجن دیاں آیاں، اکھیاں چوں نِیر وسدا‘‘ سنتے رہتے، روتے رہتے اور سو جاتے۔
مذہب اور تصوف، اداسی اور تنہائی کے سہارے تھے۔ لیکن کامل سہارے نہ تھے! کامل سہارا کوئی جیتا جاگتا غم خوار انسان ہی ہوتا ہے یوں وہ صوفیا کے مزارات پر حاضری دیتے، کبھی مساجد میں تادیر بیٹھے رہتے۔ حتیٰ کہ دنگل اور بیساکھی کے میلے میں بھی جاتے لیکن اُداسی ان کے ساتھ ساتھ چلتی۔ زندگی کا ساتھی عجیب موڑ پر انہیں تنہا کر گیا تھا۔ ایک خوش شکل، خوش پوش اور خوش خوراک شخص کی باقی ماندہ جوانی تنہائی کے عذاب میں کٹتی رہی۔ ہم سب دیکھتے ، آہیں بھرتے لیکن کچھ کر نہ سکتے تھے۔ شاید یہ ہماری کوتاہی تھی۔ ہمیں مزید کوشش کرنی چاہئے تھی۔
ابو ایک طاقتور اور دلیر شخص تھے۔ بوقت ضرورت لڑنے بھڑنے اور ہاتھ چلانے سے گریز نہ کرتے تھے۔ ان کے جسم پر دو بڑے زخموں کے نشانات تھے ایک خنجر کا اور دوسرا پستول کی گولی کا۔خنجر کا زخم گردن سے ذرا نیچے کندھے پر تھا۔ اُس وقت ہم چھوٹے تھے اور وہ گائوں کی کوئی لڑائی تھی۔ اتنے گہرے زخم کے باوجودجب وہ گھر آئے تو مکمل حوصلے میں تھے۔ گولی کا زخم ڈاکوئوں کے ساتھ مڈبھیڑ کی یادگار تھی۔ یہ 2004ء کا واقعہ ہے۔ ماڈل ٹائون گوجرانوالہ کے مکان میں ہماری رہائش تھی۔ ڈاکو بیرونی دیوار پھلانگ کر گیراج میں چھپے ہوئے تھے۔ ابو حسبِ عادت فجر سے پہلے بیدار ہوئے۔ مسجد جانے کے لئے گیراج میں آئے ہی تھے کہ دو ڈاکوئوں نے انہیں گن پوائنٹ پر رکھ لیا۔ وہ ابو کو واپس رہائشی حصے میں لے جانا چاہتے تھے۔ تا کہ اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لُوٹ مار کریں۔ ابو جی خوف زدہ ہوئے بغیر ان پر پل پڑے اور تھپڑوں، لاتوں، مُکوںکی بارش کر دی۔ ایک ڈاکو نے گولی چلائی جو کندھے سے ذرا نیچے لگ کر آر پار ہو گئی۔ گولی لگنے کے بعد بھی ابو ان کو پکڑنے اور جکڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ ایک ڈاکو کی جیکٹ ابو کے ہاتھ میں رہ گئی اور ڈاکو بھاگ گئے۔ اسی جیکٹ کی مدد سے ان کی شناخت ہوئی اور وہ گرفتار ہوئے۔
ڈاکوئوں کے فرار کے بعد ابو سکون سے اندر آئے اور بھائی سے کہا : ’’مجھے ہسپتال لے چلو، گولی لگ گئی ہے۔‘‘ اتنے سکون سے کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔
عمر کے آخری برسوں میں ان پر کئی بیماریاں حملہ آور ہوئیں۔ جگر کا کچھ مسئلہ ہوا تو کہنے لگے۔ کچھ فکر نہ کرو۔ جو بندہ محنت مشقت کا عادی ہو اُسے ستّے ای خیراں‘‘۔ذیابیطس ہو گئی تو ہم سب پریشان ہوئے لیکن وہ پرسکون تھے۔ میٹھا انہیں مرغوب تھا۔ بہو سے کہتے ’’میری چائے پھیکی رکھنا‘‘ کچھ دیر بعد ہی فریج سے گلاب جامن نکال کر کھاتے ’’پکڑے‘‘ جاتے!
پھر ہم ے دیکھا کہ ان کا کسرتی، ورزشی، مشقتی جسم رفتہ رفتہ گھلنے لگا۔ پھر ا ن کو پراسٹیٹ غدود کا مسئلہ بن گیا ۔ اس کا دوبار آپریشن ہوا۔ دونوں بار آپریشن سی ایم ایچ میں ہوئے اور میں پاس تھا۔ وہ آپریشن تھیٹر جانے سے پہلے اپنی گھڑی اتارتے، قمیص اور بٹوا میرے حوالے کرتے اور درود شریف پڑھتے ہوئے۔ آپریشن تھیٹر میں چلے جاتے۔ ذرّہ برابر خوف یا گھبراہٹ میں نے ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھی۔ البتہ فالج سے وہ پریشان ہوئے۔ انہیں یہ قبول کرنے میں کئی ماہ لگ گئے کہ میرا بازو اور ٹانگ اب میری بات نہیں مانتے۔ خاصے رنجیدہ و دل شکستہ ہو گئے۔ وہ چلتے پھرتے صحت مند تھے۔ بستر سے لگے تو کمزور ہوتے چلے گئے۔
ابو جی نے زندگی میں ہی زیادہ تر اثاثے اپنی منشا کے مطابق اپنی اولاد میں تقسیم کئے۔ وہ خاندان کے پہلے صاحبِ ثروت فرد تھے۔ جنہوں نے بیٹیوں کو بھی مکمل شرعی حصہ دیا۔ اس کے علاوہ ایک مدرسہ قائم کیا جہاں بچیوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس مدرسے کے جملہ اخراجات وہ خود برداشت کرتے تھے۔ ان کے بعد یہ صدقہ جاریہ ان کی اولاد جاری رکھے ہوئے ہے کئی مساجد میں ماہانہ عطیات اور مساکین کے مستقل وظائف انہوں نے جاری کئے ہوئے تھے۔
کبھی کبھی ابوجی ہم سب بہن بھائیوں کو پاس بٹھا کر اپنی زندگی کا تجربہ ، نکاتِ دانش کی شکل میں دان کرتے تھے۔ چند موتی ملاحظہ ہوں۔
۔ جو لڑکا دوستوں میں بیٹھ کر باپ کی شکایتیں کرے وہ خاندانی نہیں ہوتا۔ اس طرح جو لڑکی پڑوسن کے سامنے ماں کی برائی کرے وہ گھر کی وفادار نہیں۔
۔ جو شخص بات کرتے ہوئے بات بے بات ہنستا رہے وہ دانش مند نہیں ہوتا۔
۔ ماں سے بڑھ کر پیار جتلانے والی کُٹنی ہوتی ہے۔
امی کی طرح ابو کو بھی بے شمار پنجابی اکھان (اقوال) یاد تھے جنہیں وہ موقع محل کی مناسبت سے گفتگو میں استعمال کرتے تھے۔ سلطان باہو اور بلھے شاہ کے اشعار، ہیر وارث شاہ کے کچھ حصے، بے شمار اردو پنجابی نعتیں اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا مقبول زمانہ سلام، مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام‘‘ انہیں یاد تھا۔ سیاست کی خبروں سے انہیں چڑتھی۔ کہتے ’’یہ سارے ایک جیسے ہی ہیں۔‘‘ جرائم کی خبریں افسوس آمیز توجہ سے سنتے تھے۔
آخری دو سال ان کی صحت زیادہ خراب رہی۔ پھر بھی وہ اکثراوقات اپنی قائم کردہ ’’ریاست‘‘ یعنی فیکٹری میں جاتے۔ فخر سے دفتر میں بیٹھتے۔ سائلوں کو خیرات دیتے۔ کبھی دفتر سے اٹھ کر ورکشاپ میں کاری گروں کے پاس چلے جاتے۔ ڈانٹ ڈپٹ کرتے۔ اپنی ’’ایجاد کردہ‘‘ مشینوں کو دیکھتے اور خوش ہوتے۔ دراصل انہوں نے اپنی ذاتی اُپج اور قوتِ تخلیق سے کئی مشینوں میں تبدیلیاں کی تھیں، کچھ آلات اور اوزار خود بنائے تھے جنہیں وہ ’’جگاڑ‘‘ (Innovation) کہتے تھے۔ ان کے اندر چھوٹا موٹا مکینیکل انجینئر تھا۔ کوئی مشین خراب ہوتی تو اُسے خود ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے۔ معمولی پڑھا لکھا ہونے کے باوجود ورنیر کیلیپر اور مائیکرومیٹر کی مدد سے باریک سے باریک پیمائش کر سکتے تھے۔ الیکٹرک موٹر کی محض آواز سن کر اس کا نقص بتا دیتے تھے۔
انہوں نے زندگی کو صفر سے شروع کر کے کروڑوں تک پہنچایا تھا۔ انہیں اس بات کا اچھا خاصا احساس تھا۔ وہ بات بے بات یہ ذکر کر کے اپنی تعریف سننے کے متمنی رہتے۔ ہم بھی ان کی دل کھول کر تعریف کرتے جس پر وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے اور مسکراتے رہتے۔
کسی دن طبیعت خراب ہوتی تو کہتے مجھے کارخانے لے چلو، میں ٹھیک ہو جائوں گا۔ کبھی کہتے مجھے فلاں پلاٹ دکھا لائو۔ فلاں جائیداد پر لے جائو۔ اپنی فتوحات اور کامیابیوں کی مسرت کسے نہیں ہوتی؟ واپسی پر کسی نہ کسی مسجد میں نماز ادا کرتے، شکرانے کے نوافل پڑھتے۔ کبھی قبرستان جاتے، ماں، بیوی اور باپ، دادا کی قبروں پر تلاوت کرتے۔ پھر گائوں کی اس قدیمی مسجد میں بیٹھے رہتے جہاں بچپن میں جایا کرتے تھے۔
وفات سے چھ آٹھ ماہ قبل ہم نے محسوس کیا کہ ان کی یادداشت متاثر ہونے لگی ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا وہ ڈیمنشیا (Dementia) کا شکار ہو رہے تھے۔ ان کی گفتگو بے ربط ہوتی گئی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بھولنے لگے۔ رفتہ رفتہ زندگی بھر کی عادت، سگریٹ نوشی، بھی فراموش ہو گئی۔ یوں ہوتا کہ ایک پل وہ بالکل درست بات کرتے۔ اگلے ہی لمحے ماضی کے دور دراز سفر پر نکل جاتے۔ بچپن کے دوستوں کے نام لیتے۔ کھیتوں، گلیوں کا ذکر کرتے۔ کبھی فوت شدگان کو یاد کرتے کہ ابھی مجھ سے مل کر گئے ہیں۔ دراصل وہ اپنے بچپن میں چلے گئے تھے۔ کسی وقت تو انہیں بھول ہی جاتا کہ وہ شادی شدہ اور صاحب اولاد ہیں۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں کا ایسے تذکرہ کرتے جیسے وہ بچے ہوں۔ کبھی اس زمانے سے دس پندرہ برس آگے آجاتے۔ کہتے ہیں کہ گزری زندگی کا ایک ایک پل ذہن انسانی میں محفوظ ہوتا ہے۔ بس وہ بیتے پلوں کو پھر سے جی رہے تھے۔
جو شخص زندگی بھر صاحبِ ارادہ و عمل رہا ہو، جسے ہم نے ہمیشہ طاقت و اختیار سے لیس دیکھا ہو، اسے یوں بے دست و پا اور بے ربط دیکھنا اذیت ناک مرحلہ تھا۔ ایک دن تو دل چیر دینے والا واقعہ ہوا۔میں پاس بیٹھا ان کی ٹانگ دبا رہا تھا کہ اچانک بولے ’’ماں سے مل آئے ہو؟‘‘ میں اس بات کا کیا جواب دیتا، بس یہ ہوا کہ آنسو اندر گرنے لگے۔ ماں کو مرے ہوئے تو بائیس سال ہو چکے تھے۔ ان کی ذہنی حالت کا ادراک کرتے ہوئے میں نے کہہ دیا ’’جی ابو جی، امی سے مل آیا ہوں۔‘‘ درد بھرے لہجے کہنے لگے ’’اسے کہنا اگر مجھے سے ناراض ہے تو ناراض رہے، میری خیرہے، بچوں سے تو ملتی رہے۔‘‘
میری تو چیخیں نکل گئیں۔ ابو جی کو ان کے ذہن نے سُجھا دیا تھا کہ امی ان سے ناراض ہو کر کہیں اور رہتی ہیں اور ان سے ملنے نہیں آتیں۔
تئیس سال کی تنہا، مجرد زندگی اور رگ رگ میں گُھلتے ہجر نے ان کے تصورات کو کن پرچھائیوں کی شکل دے دی تھی۔ میں ان کے ہاتھ چومتا جاتا اور روتا جاتا تھا۔ وہ ایک بے نیاز خاموشی اور بے نام حیرت سے مجھے دیکھتے جاتے تھے۔
مائے نی مائے میرے گیتاں دے نیناں وچ برہوں دی رڑک پوے ۔ ادھی ادھی راتیں اُٹھ رون موئے متراں نوں، مائے سانوں نیند نہ پوے آخری دنوں میں وہ خالی خالی نظروں سے چھت کو تکتے رہتے تھے۔ پوتوں، پوتیوں اور نواسوں، نواسیوں کو کبھی پہچان لیتے اور کبھی ایک ٹک دیکھتے جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ کوئی بیٹا یا بیٹی سامنے آتی تو کسی وقت فوراً نام لے لیتے اور کسی وقت اجنبیت سے تکتے رہتے۔ ایسے میں اشکوں کی جھڑیاں لگ جاتیں۔ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو سی ایم ایچ گوجرانوالہ میں منتقل کر دیے گئے۔ جہاں وہ تین دن آکسیجن کے سہارے زندہ رہے اور تین اپریل 2021ء کی صبح خاموشی سے انتقال کر گئے۔
وہ اپنی وفات سے کئی ماہ قبل اس دن کا ذکر کرتے بلکہ ہدایات دیتے رہے تھے۔ کہتے تھے میں فوت ہو جائوں تو مجھے فلاں طریقے سے فلاں جگہ رکھنا۔ وہی کفن دینا جو میں مدینہ پاک سے لایا ہوں۔ فلاں عالمِ دین میرا جنازہ پڑھائے اور کچھ بھی ہو جائے، مجھے میرے گائوں گوندلانوالہ کے قبرستان میں دفن کرنا ۔ میں وہیں کی مٹی ہوں۔ اس مٹی میں ملانا۔
اب ان کی قبر یہ جاتا ہوں تو وہ ساری باتیں زندہ ہونے لگتی ہیں جو عمر بھر ہم ان سے سنا کئے۔ ساتھ ہی کانوں میں باپ کی لاش پر بیٹیوں کے بین بلند ہوتے ہیں اور آنکھیں آنسوئوں سے بھر جاتی ہیں۔
شہزاد نیّرؔ